Payaz k Chilkay
احوال واقعی ممتاز مفتی
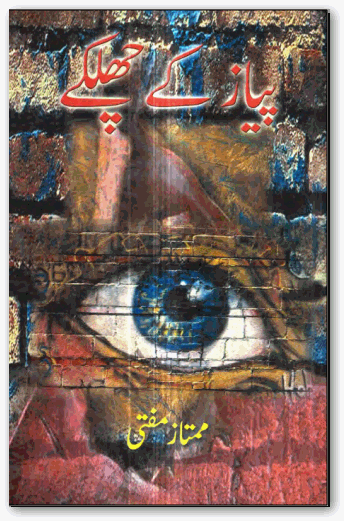
اردو ٹیکسٹ: ابو حیان
میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو زندگی گزارتے ہیں بلکہ ان میں سے ہوں جن پر زندگی گزرتی ہے۔ زندگی بھر میں نے راہ نکالی نہیں۔ راستے آتے گئے اور میں انہیں ناپتا رہا۔ چار اک بار راستہ پیدا کرنے کے مواقع آئے لیکن جو طبعی طور پر راہ ناپنے پر مجبور ہو اسے کیا کہیے۔ ادب کی دہلیز پر بھی میں ان جانے میں آ پہنچا۔ اور پھر دفعتاً شہرت کی ایک پھلجھڑی سی چل گئی، اور میں اچنبے میں رہ گیا۔ مشرقی پنجاب کے ضلع گو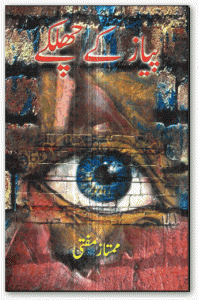 رداس پور بٹالہ ایک پرانا تاریخی شہر ہے۔ 12 ستمبر 1905 کو میں بٹاسلے میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کی تمام تر اہمیت زمانہ ماضی سے وابستہ تھی اور وہ بھی بعید۔۔زمانہِ حال نے بتالہ کے مفتیوں سے وفا نہ کی، محلے میں اس ماضی کے واضح آثار جابجا بکھرے ہوئے تھے، سر بلند چونے گچی رنگ محل دیواروں پر رنگین طغرے اور فارسی اشعار کے کتبے تہہ در تہہ طاقچے۔ خفیہ تہ خانے بوریوں میں بھری ہوئی کرم خوردہ قلمی کتابیں اور محلے کی بوڑھیوں کے وردِ زبان لا متناہی پارینہ داستانیں۔۔
رداس پور بٹالہ ایک پرانا تاریخی شہر ہے۔ 12 ستمبر 1905 کو میں بٹاسلے میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کی تمام تر اہمیت زمانہ ماضی سے وابستہ تھی اور وہ بھی بعید۔۔زمانہِ حال نے بتالہ کے مفتیوں سے وفا نہ کی، محلے میں اس ماضی کے واضح آثار جابجا بکھرے ہوئے تھے، سر بلند چونے گچی رنگ محل دیواروں پر رنگین طغرے اور فارسی اشعار کے کتبے تہہ در تہہ طاقچے۔ خفیہ تہ خانے بوریوں میں بھری ہوئی کرم خوردہ قلمی کتابیں اور محلے کی بوڑھیوں کے وردِ زبان لا متناہی پارینہ داستانیں۔۔
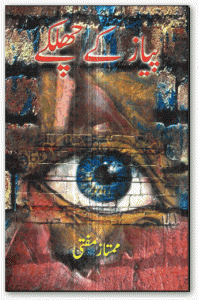 رداس پور بٹالہ ایک پرانا تاریخی شہر ہے۔ 12 ستمبر 1905 کو میں بٹاسلے میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کی تمام تر اہمیت زمانہ ماضی سے وابستہ تھی اور وہ بھی بعید۔۔زمانہِ حال نے بتالہ کے مفتیوں سے وفا نہ کی، محلے میں اس ماضی کے واضح آثار جابجا بکھرے ہوئے تھے، سر بلند چونے گچی رنگ محل دیواروں پر رنگین طغرے اور فارسی اشعار کے کتبے تہہ در تہہ طاقچے۔ خفیہ تہ خانے بوریوں میں بھری ہوئی کرم خوردہ قلمی کتابیں اور محلے کی بوڑھیوں کے وردِ زبان لا متناہی پارینہ داستانیں۔۔
رداس پور بٹالہ ایک پرانا تاریخی شہر ہے۔ 12 ستمبر 1905 کو میں بٹاسلے میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا جس کی تمام تر اہمیت زمانہ ماضی سے وابستہ تھی اور وہ بھی بعید۔۔زمانہِ حال نے بتالہ کے مفتیوں سے وفا نہ کی، محلے میں اس ماضی کے واضح آثار جابجا بکھرے ہوئے تھے، سر بلند چونے گچی رنگ محل دیواروں پر رنگین طغرے اور فارسی اشعار کے کتبے تہہ در تہہ طاقچے۔ خفیہ تہ خانے بوریوں میں بھری ہوئی کرم خوردہ قلمی کتابیں اور محلے کی بوڑھیوں کے وردِ زبان لا متناہی پارینہ داستانیں۔۔دادا جوانی میں رحلت کر گئے تھے۔ والد صاحب کی پرورش پردادا نے کی تھی۔ وہ لاہور کی ایک معروف درسگاہ میں معلم تھے۔ شاہی مسجد اور قلعہ کے درمیان فصیلی دیوار کے ان حجروں میں یہ درسگاہ قائم تھی جو آج بھی جوں کی توں قائم ہیں۔ آبا مغلوں کے دربار میں میر منشی تھے۔ جہاں انہیں مفتی کا لقب عطا ہوا تھا۔ والد صاحب محکمہ تعلیم میں ملازم تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا ےو وہ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے
گھر کے متعلق میرے بچپن کے تاثرات کچھ ایسے ہیں جیسے۔۔ گھر تو تھا لیکن وہ گھر نہیں تھا۔ جیسے ہم گھر میں نہیں بلکہ آؤٹ ہاؤس میں رہتے تھے۔ یہ آؤٹ ہاؤس گھر کے اندر واقع تھا۔ لیکن گھر آؤٹ ہاؤس سے کوسوں دور تھا۔ لہذا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ کوئی سننے والا نہ تھا۔ کوئی اہمیت نہ تھی۔ گھر میں صرف دو شخصیتیں اہم تھیں۔ ”ابا اور نئی امی” وہ دونوں گھر میں رہتے تھے۔ آؤٹ ہاؤس میں تین افراد تھے۔ اماں بڑی بہن اور میں، شاید اسی لئے آؤٹ ہاؤس میں پرورش پانے والا لڑکا گونگا تنہا اور بے چارہ ہی رہا۔ والد صاحب خوش گفتار تھے۔ رنگیلے تھے۔ اس لئے میرے تخیل کے ہیرو تھے۔ ” نئی امی” ہیروئن تھی۔ ہیرو سے فخرِ احترام ڈر اور عداوت کے جذبات منسلک ہوگئے۔۔ ہیروئن سے غم و غصہ اور بے انداز کش۔ اس بھنور میں ایسا گرا کہ سال ہا سال ڈبکیاں کھاتا رہا۔
باہر گلی میں لڑکے تو تھے۔ لیکن جھجک اور علیحدگی کے جذبات کی وجہ سے انت ساتھی نہ بنا سکا۔ یوں گلی اور محلہ گھر کی طرح ویران ہی رہے۔ مدرسہ میں بھی والد ہی کرسی نشین تھے۔ ہر سال بغیر کہے کہلائے رعائتی پاس ہوجانا یقینی تھا۔ لہذا پڑھنے سے چھٹی ہو گئی۔ نہ طلب پیدا ہوئی اور نہ علم حاصل ہوا۔ میٹریکولیشن کے بعد اس ازلی جھجک کی وجہ سے اسلامیہ کالج راس نہ آیا۔ پی ڈی پی ایم کالج انبالہ اور اس کے بعد ہندو سبھا کالج امرتسر میں پناہ لینی پڑی۔ وہاں کچھ بات چل نکلی لیکن پڑھائی میں وہی بے دلی قائم رہی۔ 1927 میں پھر سے اسلامیہ کالج لاہور میں تھرڈ ایر کا داخلہ لیا۔ جھجک تو اب بھی موجود تھی لیکن اسکی دھار میں وہ کاٹ نہ رہی۔
ان دنوں اتفاق سے ایسے شخص کے قریب رہنے کا موقع مل گیا جس میں طلب علم کا شوق دیوانگی کی حثیت اختیار کئے ہوئے تھا۔ اس قرب کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک بیداری سی پیدا ہوگئی۔ اس کا نام فیاض محمود تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے فیاض محمود ایک جزیرہ تھا۔ تن تنہا۔ طنز اور تیوری سےمسلح۔ وہ کسی کو قریب آنے نہیں دیتا تھا
کوئی آنے کی کوشش کرتا تو طنز کے طمنچے سے گولیاں چلتیں۔ جاپہنچتا تو طلبِ علم پیر تسمہ پاکی طرح شانوں پر سوار ہوجاتی۔ پتہ نہیں کیسے میں فیاض محمود کے پاس جا پہنچا۔ فیاض محمود کے قرب کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بے مقصد مطالعہ کی لذت سے آشنا ہوا۔
کوئی آنے کی کوشش کرتا تو طنز کے طمنچے سے گولیاں چلتیں۔ جاپہنچتا تو طلبِ علم پیر تسمہ پاکی طرح شانوں پر سوار ہوجاتی۔ پتہ نہیں کیسے میں فیاض محمود کے پاس جا پہنچا۔ فیاض محمود کے قرب کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں بے مقصد مطالعہ کی لذت سے آشنا ہوا۔
دوسری شخصیت جس سے میں متاثر ہوا۔ مجید ملک کی تھی۔ مجید ملک بنیادی طور پر شاعر تھے۔ انکی شخصیت میں رنگینی اور رکھ رکھاؤ کا عجیب امتزاج تھا۔ ان کا مزاج محبوبانہ تھا انداز رندانہ۔ مجید ملک میری زندگی میں سکندر اعظم کی طرح آئے تھے اور چلے گئے۔ لیکن ان کی شخصیت کی رنگینی دیر تک قائم رہی جیسے غروبِ آفتاب کے بعد دیر تک افق پر رنگ کی دھاریاں قائم رہتی ہیں۔
1929a میں، میں نے بی اے پاس کیا۔ یہ وہ دور تھا جسے مالی انحطاط کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اقتصادیات کے ماہرین کا خیال تھا کہ مالی انحطاط پہلی جنگِ عظیم کی وجہ سے ہے۔ پہلی جنگِ عظیم مدت سے ختم ہو چکی تھی۔ سانپ گزرے دس سال بیت چکے تھے۔ لکیریں اب ابھر رہیں تھیں۔ بی اے میں اقتصادیات پڑھنے کے باوجود یہ معمہ سمجھ میں نہ آیا۔ کہا جاتا تھا یہ انحطاط عالمی ہے۔ بر صغیر میں یہ حالت تھی کہ تمام مقابلے کے امتحانات منسوخ ہوچکے تھے۔ دفتروں میں تخفیف کا کلہاڑہ چل رہا تھا۔ تنخواہوں میں کاٹ ہو رہی تھی۔ نوجوانوں کے لئے ملازمت حاصل کرنا ناممکن تھا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے دور کے تمام نوجوان اس انحطاط کی بھینٹ چڑھ گئے۔
بی اے کے بعد میں نے سٹینو گرافی کی۔ اس زمانے میں بی اے سٹینو گرافر خال خال سے بھی کم تھے۔ کمشنر راولپنڈی نے میرا کام جانچا پسند کیا اور سٹینو بنا لیا۔ یہ آسامی بڑی حثیت کی آسامی تھی۔ صرف دقت یہ تھی کہ تنخواہ کے بغیر کام کرنا پڑتا تھا۔ چونکہ ابھی آسامی کی منظوری نہیں ہوئ تھی۔ یہ جان کر کہ مجھے اس آسامی پر کام کرنا منظور نہیں دفتر والے بے حد حیران ہوئے، انہوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ برخودار ایسے سنہری مواقع زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ لیکن میری سمجھ میں نہ آیا کہ بغیر تنخواہ کی نوکری کو کس لحاظ سے سنہری موقع سمجھا جا سکتا ہے۔ ان دنوں مجھے بالائی آمدنی کی اہمیت کا شعور نہ تھا۔
تنخواہ والی ملازمت حاصل کرنے کے لئے مجھے فنِ معلّمی سیکھنے کے لئے سنٹرل ٹریننگ کالج میں داخل ہونا پڑا۔ بی ٹی میں مجھے داخلہ نہ ملا۔ چونکہ میرے مضامین سکول سے متعلق نہ تھے۔ بی اے میں نے فلسفہ اور اقتصادیات میں کیا تھا۔ اردو فارسی اور عربی سے قطعی ناواقف تھا۔ بعد میں مشکل سے مجھے ایس۔اے۔وی میں داخلہ ملا۔
ابھی تک فیاض محمود سے میل جول قائم تھا۔ بے غرض مطالعہ کا سلسلہ قائم تھا۔ پھر محبت کا اک رنگین بلبلہ پھوٹا۔ میں نے مزید شدت سے کتاب میں پناہ لی۔ مطالعہ کا یہ جذبہ مثبت نہ تھا۔ مقصد فرار تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس میں دیوانگی کا عنصر پیدا ہوا۔ ادھر دیوانگی پر بہار آئی۔ ادھر ان دنوں پنجاب پبلک لائبریری جوبن پر تھی۔ ہمارا میل ہوگیا۔اور پھر خوب گزری۔ ابتدا میں میں نے مطالعہ لٹریچر سے شروع کیا۔ لیکن طبعی جمود کی وجہ سے ادب کی رنگینی راس نہ آئی۔ اس لیے سنجیدہ چیزوں کی طرف چل نکلا، کانٹ برٹرینڈر سل ہالڈین، نٹشے، برگساں، فرایڈ جیسی سنجیدہ چیزوں نے میری پیشانی پر تیوری چڑھا دی۔ پھر جب اسکا احساس ہوا تو فلسفے کو چھوڑ کر نفسیات کی طرف آپہنچا۔ لٹریچر میں کافکا اور داستو وسکی کھا گئے۔ کافکا اور داستووسکی میں وہی بے بسی وہی بے چارگی وہی اکیلا پن تھا۔ ایک مناسبت سی تھی یا شاید اس لئے کی داستووسکی میں مجھے زندگی کا تضاد ملا۔
داستووسکی کے کردار ایک ہی ساعت میں ہنستے بھی تھے روتے بھی تھے۔ حاتم میں بخل ابھرتا۔ طائفہ میں سے راہبہ جھانکتی، خود پرست قربانی کے جذبے سے سرشار ہو جاتا۔ سورما خوف سے تھر تھر کانپتا۔ بھڑوں کی بھن بھن کرتے ہوئے رنگارنگ الٹے سیدھے متضاد جذبات کی بھیڑ میں مجھے زندگی کی جھلک دکھائی دی۔
1931 میں سنٹرل ٹریننگ کالج سے فارغ ہوا تو انحطاط کا وہ عفریت اور بھی بھیانک ہو چکا تھا۔
پروفیسر کی تنخواہ 120 سے 65 تک گر چکی تھی۔ سینئر انگلش ٹیچر کی 80 سے 45 تک اور ملازمت حاصل کرنا مشکل ہو چکا تھا۔
ٹریننگ کالج میں جدید طریق تعلیم و تربیت کا مطالعہ کرنے کے بعد سکول میں پڑھانے کی آسامی مل گئی۔ سکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے پاس بٹھا کر بڑے پیارومحبت سے مجھے سمجھایا۔ بولے دیکھ بچے۔ بچوں کو نئے نفسیاتی اصولوں کے مطابق پڑھات کی کوشش نہ کرنا۔ بیٹا یہ کتابی باتیں زندگی میں نہیں چلتیں۔ یہ ہاتھی کے دانت صرف دکھانے کے لئے ہیں۔
بارہ سال مختلف مدرسوں کا ماحول میرے لئے یوں تھا۔ جیسے استوائی خطے کے کسی جانور کو قطب شمالی میں جاکر چھوڑ دیا ہو۔ اساتذہ بڑے معقول حسین اور وضع دار تھے۔ اگر نہیں تھے تو بھی ایسا دکھنے کی شدید کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ وہ ذاتی اہمیت سے پھولے ہوۓ تھے۔ اپنے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھتے تھے۔ رسمی وقار کی بوجھل گٹھڑی اٹھائے بغیر ایک قدم نہ اٹھا سکتے تھے۔ قہقہہ لگانے کی جگہ مسکرانا کافی سمجھتے تھے۔ مسکرانے کی جگہ گھورتے۔ طے شدہ باتوں کے متعلق سوچنا ان کے نزدیک جرم تھا۔ اور ہٹ کر بات کرنے والا مشتبہ تھا۔ ان کے نزدیک میری حثیت ہمیشہ قدرے دلچسپ مگر بیشتر مشکوک رہی۔ اگر میں نے بارہ سال مدرسے کے ماحول میں بسر کئے تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ازلی طور پر راہ ناپنے والا تھا، راستہ بنانے والا نہیں۔
اس دور میں صرف ایک ساتھی ملا۔ جس نے میری زندگی پر بہت اثر ڈالا۔ محکمہ تعلیم میں وہ میرا ہم کار تھا۔ میاں حفیظ الرحمن بلا کا ذہن رکھتا تھا۔ اسکی شخصیت میں رنگ کی دھاریاں تھیں۔ اس نے مجھے کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری پڑھنے کی لت ڈالی۔ میاں اور میرا ساتھ پندرہ برس تک رہا۔
ان ہی دنوں ایک بار چھٹیوں میں والد صاحب سے ملنے ملتان گیا تو وہاں میری ملاقات ن م راشد سے ہوئی۔ ان دنوں وہ بھی نذر محمد تھے۔ اور میں ممتاز حسین تھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ شاید ہماری واقفیت علیک سلیک تک محدود رہتی۔ لیکن ہم دونوں کے والد محکمہ تعلیم میں تھے اور دفتر میں ایک دوسرے سے بر سرِ پیکار تھے۔لہذا راشد اور میں قریب تر ہو گئے۔ ان دنوں راشد ”تائیس” یا شاید ”افروداتاتیس” کا اردو ترجمعہ کر رہے تھے۔ انہیں فارسی اور اردو میں دسترس حاصل تھی۔ میں دونوں میں کورا تھا۔ ہمارے درمیان گفتگو کا واحد موضوع نفسیاتی زاویے تھا۔انہی دنوں راشد کے ایک دوست کو جو ملتان سے ایک اردو جریدہ ”نخلستان” مرتب کرتے تھے۔ ناگاہ باہر جانا پڑا۔ پرچے کی ادارت وہ راشد کے زمے کر گئے۔ راشد نے صفحات پُری کےلئے مجھ سے لکھنے کو کہا۔ اردو میں لکھنا میرے لئے ناممکن تھا۔ بہر صورت میں نے کوشش کی۔ ایک اردو فلم ”ہیٹیلی دلہن” پر طنز لکھی، یہ طنز ہمارے ہیڈماسٹر صاحب کی نگاہ چڑھی۔ انہوں نے گوجرہ ہائی سکول کے میگزین کے سالنامے کے لئے فرمائش کی۔ افسر کا حکم کیسے ڈالتا۔ گھر کے موضوع پر ایک مضمون”الجھاؤ” لکھا پھر پتہ نہیں کیسے منصور احمد نے جو ادبی دنیا کے ایڈیٹر تھے۔ سالنامے کے لئے مختصر افسانہ مانگا۔ 1936 کے سالنامے میں میرا پہلا مختصر افسانہ ”جھکی جھکی آنکھیں” ایک لمبے چوڑے تعریفی نوٹ کے ساتھ چھپا۔ دیکھ کر دل میں ایک پھلجھڑی سی چل گئی۔ چھ مہینے بعد چھپنے یا لکھنے کی خواہش نے انگڑائی لی۔ ایک کہانی لکھ کر ادبی دنیا کو بھیجی۔ اس دوران میں منصور احمد ناگہانی طور پر انتقال کر چکے تھے اور ادارت کے فرائض عاشق بٹالوی سر انجام دے رہے تھے۔میری کہانی مجھے لوٹا دی گئی۔ مسودہ سرخ سیاہی سے رنگا ہوا تھا۔ منسلکہ خط میں لکھا تھا۔”اگر آپ ترجمہ کی جگہ کوئی طبع زاد چیز لکھیں تو بہتر رہے”
اگر خالی مسودہ ہی لوٹا دیا جاتا تو شاید مجھے دھچکا لگتااور لکھنے کی یہ عیاشی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی۔ لیکن اس منسلکہ خط نے مجھے بچا لیا۔اس زمانے میں دلی سے ایک نیا پرچہ ساقی نکلا تھا، میں نے وہ ساقی کو بھیج دی۔ اور وہ جوں کی توں چھپ گئی۔ اس کے بعد ساقی کو میں نے کئی ایک چیزیں بھیجیں۔ شاہد احمد میں یہ خوبی تھی کہ نہ تو وہ تعریفی نوٹ چھاپنے کی شوقین تھے نہ تصحیح کے۔ ان کے خطوط کاروباری انداز کے حامل ہوتے تھے۔
پھر ادبی دنیا میں مولوی صلاح الدین اور میرا جی آگئے۔ اتفاقاً ان سے ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے مجھ سے کئی ایک چیزیں لکھوائیں۔ اور ان پر تبصرے چھاپے یوں لکھنے اور چھاپنے کا دھندا شروع ہو گیا۔ اس کے باوجود میری زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ شہرت لائم لائٹ نہ بنی۔ قصور میرا اپنا تھا۔ نہ میں نے ادبی حلقوں کی طرف رجوع کیا نہ پبلشروں سے ملا۔ نہ اپنی تحریروں کے بارے میں تذکرہ کیا۔ مدرسے میں میں ممتاز حسین تھا۔ لکھنے والا مفتی تھا۔ کسی محفل میں دونوں کا کبھی میل نہ ہوا۔
دیر تک مدرسہ میں کسی کو علم نہ ہوا کہ میں لکھتا ہوں اور جب ہوا تو اساتذہ نے پاس بٹھا کر کمال شفقت سے مجھے سمجھایا۔ کہنے لگے میاں ادب پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ سنجیدگی اور متانت نہ ہو تو ادب نہیں ہوتا۔ اس بے ادبی کو چھوڑو اور اگر ضرور لکھنا ہے تو پاکیزگی موضوع چنو۔ مثلاً مذہب ہے، اخلاق ہے۔
اس کے بعد مدرسے میں میرے ہمکار مجھے قابلِ ہمدردی سمجھنے لگے اور میرے برتاؤ کی تفصیلات پر کڑی نگاہ رکھنے لگے۔ اساتذہ سے بات افسران بالا تک پہنچی۔ ایس ایم شریف ایم اے کینٹ نے مجھے خصوصی طور پر بلا کر مشورہ دیا کہنے لگے جھکی جھکی آنکھوں والیوں پر کہانیاں لکھنے سے طالب علموں پر برا اثر پڑتا ہے۔ خصوصاً جب لکھنے والا ٹیچر ہو اگر تم لکھنا ہی چاہتے ہو تو میاں انگریزی میں لکھو۔ انگریزی میں لکھنے سے بات میں معقولیت پیدا ہوجاتی ہے۔
اس زمانے میں کرشن چندر، عصمت، فیاض محمود اور بیدی کے افسانے چھپ رہے تھے۔ منٹو ابھی روسی تراجم میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ غلام عباس بھی گاہے گاہے دیکھنے میں آتے تھے۔ یہ سب لوگ ادب برائے ادب کے انداز میں لکھتےتھے۔
پھر ترقی پسندی کا شوشہ چل نکلا اور سردار کرشن چندر، فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی ابھرے۔ ہم سب کو ترقی پسند قرار دیا گیا۔ تو فرطِ انساط سے ہماری باچھیں کھل گئیں، پھر ترقی پسندی کا راز کھلا تو بڑا ہنگامہ ہوا۔ بہت چھینٹے اڑے۔ سانپ نکل گیا لکیریں آج تک باقی ہیں۔ ترقی پسندوں نے منٹو اور مجھے ادبی جریدوں سے ban کردیا۔ ادبی محاذ کرنا اپنے بس کا روگ نہ تھا۔ سودبک کر بیٹھ گئے۔ مکتبہ اردو کے مالک چودھری برکت علی پہلے پبلشر تھے۔ جن سے میری ملاقات ہوئی۔ چونکہ وہ درسی کتابوں کا کاروبار کرتے تھے۔ لہذا اکثر سکول میں آیا کرتے تھے۔ ان کے مسلسل اسرار کی وجہ سے میرا پہلا مجموعہ ”ان کہی” شائع ہوا، برکت علی خواب آدمی تھے۔ کئی ایک سال تک ہمارا ساتھ رہا۔1945 میں میں نے محکمہ تعلیم چھوڑ دیا اور ریڈیو میں ملازمت کرلی۔ 1947 میں اپنی فلم کہانی ” سلطانہ رضیہ” فلمانے کے سلسلہ میں بمبئی چلا گیا۔ تقسیم کے بعد وہاں رہنے کے لئے دل نہ مانا۔ میرے دوست احمد بشیر بھی میرے ساتھ تھے۔ وہاں ہم اندھیری میں کرشن کے ہاں ریتے تھے۔ میرا جی بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔
پاکستان پہنچ کر کئی ماہ تلاشِ روزگار کے لئے یہاں وہاں جوتے چٹخاتے پھرے۔ انہیں دنوں میری ملاقات اشفاق احمد اور اس کی بیگم قدسیہ سے ہوئی۔ اشفاق اور قدسیہ نے میرا دامن خوشی سے بھر دیا۔ آج بھی مٹھاس کی وجہ سے میری زندگی شیریں ہے۔
تقسیم کے بعد میں نے جگہ جگہ ملازمت کی۔ ہفتہ وار استقلال ہوائی فوج اور آزاد کشمیر ریڈیو پھر پبلک سروس کمیشن کے توسط سے اطلاعات میں ایک پکی نوکری مل گئی۔ اس وقت تک میرے کئی ایک مجموعے چھپ چکے تھے۔ گہما گہمی، غبارے، چپ، اسمارائیں، نظام سقہ، یہ سب مجموعے شوق کے تحت نہیں بلکہ ضرورت کے تحت چھپے تھے۔ مثلاً ایک مجموعہ بمبئی پہنچنے کے لئے کرایہ حاصل کرنے کے لئے چھپا۔ ایک مجموعہ ریڈیو سیٹ خریدنے کے لئے چھپا۔ یوں ضرورت نے مجھے صاحبِ کتاب بنا دیا۔
پبلک سروس کے توسط سے پکی نوکری ملنے کے بعد ضرورت کی دھار میں وہ کات نہ رہی۔ لہذا یہ شوق چرایا کہ مسلسل کتاب لکھوں۔ ان دنوں خوش قسمتی سے اشفاق احمد پبلشر بنے ہوئے تھے۔ سیاں بھئیے کوتوال والی بات تھی۔ 1961 میں میری مسلسل کتاب ”علی پور کا ایلی” چھپی۔ یہ کتاب افراتفری میں چھپی تھی۔ اس افراتفری کی وجہ آدم جی انعام تھا۔ انعام نہ ملا اور ”علی پور کا ایلی” اس وجہ سے مشہور ہوگئی کہ اس پر انعام نہ ملا۔ اس ضخیم کتاب کو چھاپنے کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ پبلشر کی کمر ٹوٹ گئی اور اشفاق احمد ازسر نو اپنی پرانی جگہ ادیبوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ اشفاق احمد نے ”علی پور کا ایلی” کے علاوہ میرا ایک مجموعہ ”گڑیا گھر” بھی چھاپا تھا جسے گلڈ نے اٹھا لیا اور بوریوں میں بند کرکے کسی گودام میں رکھوا دیا۔
اب ”لکھ یار” کے تقاضے پر یہ مجموعہ اشاعت کے لئے دے رہاہوں۔ ”لکھ یار” چند ادیب دوستوں کی انجمن ہے جس کا مقصد ممبروں کو لکھنے پر مائل کرنا نہیں بلکہ مجبور کرنا ہے چاہے نوبت تشدد تک پہنچے۔1958 میں میں قدرت اللہ شہاب سے متعارف ہوا۔ یہ تعارف میری ادبی زندگی کے لئے حادثہ سے کم نہ تھا۔ انہوں نے میرا زاویہ نظر یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ایسے حقائق میری نگاہ پڑے جن کے وجود سے میں قطعی طور نا واقف تھا۔ پرانے بت گر کر چور چور ہوگئے۔ افسانہ نویسی کاپایہ ستون ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دانشوری کا لبادہ تار تار ہوگیا۔ جو پاس تھا۔ وہ کھو گیا۔ جو محسوس کیا اسے صفحہِ قرطاس پر لانے کی صلاحیت نہی۔ اگر کبھی یہ صلاحیت حاصل ہوئی اور زندگی نے وفا کی تو شاید میں تفصیلی طور پر بیان کروں کہ وہ افسانہ نویس جو نفس غیر شاعر کی ان کہی کی کہانی لے کر اٹھا تھا۔ اس پر کیا بپتا پڑی۔ قدرت اللہ میری زندگی کا عظیم Experience ہے اور عظیم Experience رنگ لائے بغیر نہیں رہتا

